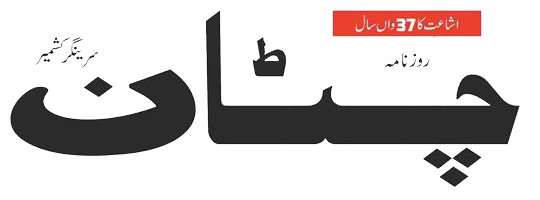تحریر:محمد حمید شاہد
شمس الرحمن فاروقی کو میں ایک مجتہد نقاد مانتا ہوں۔ ان کے کام کی کئی جہتیں ہیں۔ چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ”شعر شور انگیز“ کی صورت میں انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، یہاں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہیے اور ساتھ ہی یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ تفہیم میر کے باب میں اجتہادی کام نہیں تو اور کیا ہے؟ فاروقی صاحب کے ناقدین نے تفہیم میر کے مقابلے میں ”تفہیم غالب“ کا مختصر کام دیکھ (اور شاید محض دیکھ کر) یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی محمد حسن عسکری کی طرح میر کے طرف دار تھے اور غالب کو اپنے محبوب شاعر سے کمتر درجے کا شاعر سمجھتے تھے۔
مجھے یوں لگتا ہے کہ خود فاروقی صاحب کو ”شعر شور انگیز“ جیسا عظیم کارنامہ سر انجام دیتے وقت یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کل کو کوئی اس الزام کے ساتھ اٹھ کر سامنے آ سکتا ہے لہٰذا انہوں نے میر کی تفہیم کے ساتھ ساتھ اپنے تمہیدی ابواب میں سب سے پہلے عسکری صاحب کے خیالات کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے میر کو غالب سے بڑھا دیا لیکن میر کی برتری کے لیے جو دلائل دیے وہ خود ایسے مفروضے تھے جو محتاج دلیل ہیں۔
یہیں مجھے ان کا ایک انٹرویو یاد آتا ہے جو پہلے ”مکالمہ“ کراچی میں شائع ہوا تھا اور پھر اسے حک و اضافہ کے بعد فاروقی صاحب نے ”شب خون 261“ میں شامل اشاعت کیا تھا۔ عسکری صاحب کا خیال تھا کہ نئی غزل پر میر کے اثرات غالب کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ خود عسکری صاحب نے میر پر کئی مضامین لکھے جب کہ غالب پر مشکل سے ایک دو ۔ یوں انہوں نے غالب پر میر کو فوقیت دی تھی۔ جب اس باب میں فاروقی صاحب سے سوال کیا گیا تو ان کا موقف تھا کہ ممکن ہے ایک خاص وقت میر کا اثر نئی غزل پر زیادہ نظر آتا ہو۔
انہوں نے 1948۔ 50 کے برسوں میں غزل کے رجحانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تب کئی شعرا اپنی آواز ڈھونڈنے کے لیے میر کی طرف جا رہے تھے اور اس باب میں ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی اور ابن انشا کی مثال دی جو بہ قول ان کے اپنی آواز ڈھونڈنے کے لیے میر کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید وہاں سے انہیں کوئی راستہ ملے لیکن بعد میں ایسا نہیں رہا۔ تاہم انہوں نے یہاں یہ بھی وضاحت کی تھی کہ جن شاعروں نے میر کی پیروی کی وہ غالب کی طرح کے تعقلاتی، خیال بند شاعر نہ تھے اور انہیں تو میر کی طرف جانا ہی تھا۔
فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ صدی کی ساتویں دہائی میں غالب پرستی کا چلن عام ہوا۔ غالب کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اس کے بعد تو بڑھتی چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1960 ء کے آس پاس جب انہوں نے ادب میں قدم رکھا تھا تو فوری طور پر ان کے لیے جو جواز غالب کے یاں تھا وہ میر کے یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں غالب کی مشکل پسندی، غالب کے رویے اور اس طرح کی چیزیں انہیں زیادہ قابل قبول تھیں اور وہ میر کے مقابلے میں غالب کے زیادہ قریب تھے۔
یوں دیکھیں تو فاروقی صاحب کے ہاں ان کی پہلی محبت غالب بنتی ہے لیکن لطف یہ ہے کہ میر اور غالب کے درمیان موازنے کے دوران وہ اس رویے سے محترز رہے ہیں جو ”افسانے کی حمایت میں“ کے مباحث میں شاعری اور افسانے کے موازنے کے دوران رہا۔ وہاں اگر انہوں نے اپنا وزن شاعری کے پلڑے میں ڈال رکھا تھا تو یہاں میر ہوں یا غالب دونوں کی فنی توفیقات کے علاقے نشان زد کر رہے تھے اور ”شعر شعور انگیز“ کی جلد اول کے تمہیدی مضمون ”خدائے سخن:میر کہ غالب“ میں وہ پہلے تو خدائے سخن والی اصطلاح سے الجھتے رہے، اس کی ادبی پیمانوں پر تعبیر پر زور دیتے رہے اور پھر صاف لفظوں میں کہہ دیا: ”غالب کے ہوتے ہوئے میں میر کو خدائے سخن نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میر کے ہوتے ہوئے غالب کو بھی خدائے سخن کہنا ممکن نہیں۔“
فاروقی صاحب میر اور غالب کے اس موازنے میں جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یوں ہے :
1۔ زبان کے تنوع، تجربہ ء حیات کی کثرت، شخصیت کی ہمہ گیری اور کیفیت میں میر کا مرتبہ غالب سے اعلیٰ ہے۔ خالص تعقل اور تجرید اور نازک خیالی میں غالب کا درجہ میر سے بلند ہے۔
2۔ دونوں کے تخیل میں فرق ہے، لیکن تخیل کی شدت دونوں کے یہاں برابر ہے۔
3۔ غالب کا تخیل آسمانی ہے اور میر کا تخیل زمینی۔ یعنی غالب تجریدی (ایبسٹریکٹ) زیادہ ہیں اور میر ٹھوس اور مرئی (کنکریٹ) زیادہ ہیں۔
4۔ دونوں بے حد مضمون آفریں ہیں اور اس باب میں دونوں برابر ہیں۔
5۔ شور انگیز اشعار دونوں کے یہاں کثرت سے ہیں۔
6۔ رعایت لفظی سے دونوں کو بے حد شغف ہے۔
7۔ غالب اور میر ایک ہی طرح کے شاعر ہیں یعنی بعض مظاہر کائنات اور زندگی کے بعض تجربات کو شعر میں ظاہر کرنے کے لیے دونوں ایک ہی طرح کے وسائل استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔
8۔ دونوں شاعروں کی ذہنی ساخت اور طرز فکر میں مماثلت ہے۔
9۔ میر نے فارسی شعرا سے استفادہ کیا۔ ان کا استفادہ تحسین کی قسم کا ہے۔ غالب نے میر سے بار بار استفادہ کیا لیکن غالب کا استفادہ تقلیدی نہیں بلکہ تخلیقی ہے۔
10۔ دونوں کو شاعری سے جو توقعات تھیں وہ بڑی حد تک یکساں تھیں۔ گویا دونوں کا نظریہ شعر ایک تھا۔ غالب معنی آفرینی، شور انگیزی، مناسبت الفاظ، اور رعایت فن کو بنیادی اہمیت دیتے تھے۔ میر نے بھی شعر میں انہی خواص کو اہمیت دی ہے۔
11۔ میر کے ہاں موضوعات کی فراوانی ہے۔ غالب کے ہاں استفہام کی فراوانی میر سے زیادہ ہے اس لیے غالب کا کلام میر سے زیادہ رنگا رنگ معلوم ہوتا ہے۔
12۔ روزمرہ کی زندگی اور اس کے واقعات سے جتنا شغف میر کو ہے اتنا غالب کو نہیں۔ غالب غیر معمولی واقعات کو بھی بعض اوقات ایک انداز بے پروائی سے بیان کر جاتے ہیں۔ میر تمام واقعات کو واقعات کی سطح پر برتتے ہیں اور ان میں تجرباتی یا جذباتی معنویت اور اہمیت داخل کرتے ہیں۔
13۔ واقعات کی کثرت اور ان کی جذباتی معنویت کی بنا پر میر کی دنیا، غالب کی دنیا سے بہت مختلف نظر آتی ہے۔
14۔ میر کے سامنے زبان کے وہی نمونے تھے جو شاعری میں دستیاب تھے۔ میر نے مروج شعری زبان سے انحراف کیا اور روز مرہ سے شاعری کی زبان اخذ کی۔ غالب کا زمانہ آتے آتے اردو میں ادبی نثر وجود میں آ چکی تھی۔ وہ ایسی زبان دینا چاہتے تھے جو شاعری کی زبان ہو، یعنی جس میں علمی اور ادبی دونوں طرح کی قوتیں ہوں۔ غالب اپنی کوشش میں بڑی حد تک کامیاب رہے۔
15۔ فارسی سے شغف کے باوجود میر کے کلام کی عام فضا غالب کے کلام کی عمومی فضا سے مختلف ہے۔ غالب اکثر فارسی الفاظ و تراکیب سے اپنی شعری فضا میں اجنبیت کا عنصر داخل کرتے ہیں جب کہ غالب کا تجریدی رنگ میر کے ہاں نہیں ہے۔
16۔ میر نے زبان کے ساتھ بہ کثرت آزادیاں روا رکھی ہیں وہ موقع پڑنے پر دور دراز کے الفاظ، شاعری کی زبان کے لیے نامانوس الفاظ، یا عوامی الفاظ بے خوفی سے برت لیتے ہیں، جب کہ غالب نے زبان کو جس طرح برتا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفاست یعنی سوفیسٹیکیشن کا وہ رنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس میں پراکرت عناصر کی کارفرمائی کم سے کم ہو۔
17۔ میر اور غالب ہمارے دو شاعر ہیں جن کے یہاں عاشق کا کردار، غزل کے رسومیاتی عاشق سے مختلف ہے اور اپنی شخصیت آپ رکھتا ہے۔ دونوں نے اس انفرادیت پرست کردار کو خلق کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے کام لیا ہے۔ میر نے عاشق کو انسان بنایا غالب نے رسومیات کو شدت سے برت کر عاشق کی ہر صفت مثالی بنا دی۔ غالب اور میر کا افتراق جتنا اس میدان میں ہے اتنا کہیں اور نہیں ہے۔
18۔ میر کے ہاں جنسی مضمون دبتا نہیں بلکہ چمک اٹھتا ہے غالب کے ہاں جنسی تعلقات کا بیان بہت کم ہے۔
19۔ روانی کے اعتبار سے انیس اور اقبال کے علاوہ میر کا ہم پلہ کوئی نہیں لیکن دونوں ہی کے یہاں آہنگ میر جیسا پیچیدہ نہیں۔ غالب کی روانی میر سے کچھ کم ہے لیکن ان کے آہنگ میں پیچیدگی انیس اور اقبال سے زیادہ ہے۔
میر اور غالب کا یہ سارا موازنہ میں نے ”شعر شور انگیز“ کی جلدوں کی ابتدا میں موجود فاروقی صاحب کے مفصل مضامین سے اخذ کر کے یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تفہیم میر کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے بھی غالب ان کے ساتھ تھے۔ آگے چل کر جب وہ اشعار کی تعبیر کرتے ہیں تو بھی جہاں موقع نکلا وہ غالب کی طرف دیکھتے رہے ہیں۔ فاروقی صاحب کے ہاں، یوں لگتا ہے کہ میر اور غالب اردو غزل کا ایسا معیار ہیں کہ انہیں بھی ایک دوسرے کا حوالہ دیے بغیر ڈھنگ سے نہیں سمجھا جاسکتا۔
دوسری اہم بات خالص ادبی معیاروں پر میر اور غالب کے مابین اشتراق اور افتراق یا ایک کے مقابلے میں دوسرے کی توفیقات کو آنکنے کا مثبت رویہ ہے۔ اسی مثبت رویے کی عطا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے ان کا ذہن انہیں ایسے ایسے مقامات تک لے جاتا ہے جس کا تصور بھی عام ذہن نہیں کر سکتا۔ ”تفہیم غالب“ کے مطالعے سے بھی آپ کو اندازہ ہو گا کہ وہ کیسے دوسروں سے مختلف ہو جاتے رہے ہیں۔
٭٭٭
فاروقی صاحب نے ”تفہیم غالب“ کے دیباچے میں کہا ہے کہ 1969 ء میں غالب کی صد سالہ برسی جگہ جگہ منائی گئی لیکن غالب صدی تقریبات کا سال 1968 میں ہی شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے غالب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ”شب خون“ کے شمارہ نمبر 23 بابت ماہ اپریل 1968 ء سے غالب کے اشعار پر گفتگو کے سلسلے کو آغاز دے کر تفہیم غالب کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ 1969 ء میں غالب کی صد سالہ برسی کے بعد بھی متوجہ رہے۔ اس سلسلے کی آخری تفہیم ”شب خون“ شمارہ 151 بابت ماہ ستمبر، نومبر 1988 ء تک میں شائع ہوئی تھی۔ گویا اس کام میں ان کے بیس برس لگ گئے۔ پھر جب 2005 ء میں ”تفہیم غالب“ کی دوسری اشاعت کا مرحلہ آیا تو بھی انہوں نے اس میں بارہ اشعار کا مزید اضافہ کیا اور پہلے سے موجود اشعار کو بھی ازسر نو دیکھا۔ کہہ لیجیے جو کتاب اب ہمارے مطالعہ کے لیے دستیاب ہے اس کی مدت تصنیف بیس نہیں، سینتیس برس ہے۔
غالب کی شرحیں بے شمار لکھی گئیں اور میر کا ہر زمانے میں نئے سے نیا انتخاب شائع ہوتا رہا مگر فاروقی صاحب نے مختلف کام یہ کیا ہے کہ میر کے کلام کی شرح ”شعر شور انگیز“ کی صورت لکھ دی اور تفہیم غالب کے باب میں شارحین غالب سے جہاں چاہا خوب خوب اختلاف کر کے نئے معنی متعین کیے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے جہاں مشرقی شعریات سے مدد لی وہیں مغربی تنقیدی پیمانوں کو بھی برتا کہ وہ اس باب میں وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور ان پیمانوں کو آنکھیں کھول کر برتنے کا قرینہ اور حوصلہ بھی ان کے پاس اوروں سے کہیں زیادہ تھا لہٰذا جہاں یہ اصول کار آمد نہ تھے وہ انہیں رد کر کے از سر نو مرتب کرتے گئے۔
غالب، تفہیم غالب اور فاروقی صاحب
A
A
Related Posts
© Designed Gabfire.in - Daily Chattan