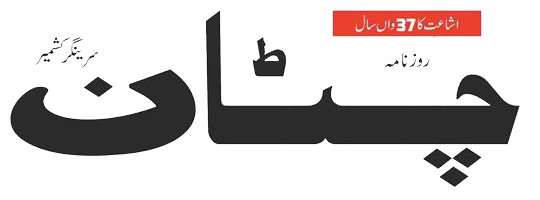تحریر:عشرت علی صدیقی
آزادی اور محکومی ایک دوسرے کی ضد ہیں اور محکومی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حاکم کی طرف سے محکوم پر بعض پابندیاں عائد کی جاتی ہیں ۔ آزادی کے خواہشمند ان پابندیوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں ۔ ہندوستان میں اسی جدوجہد کا ایک طویل دَور ۱۹۴۷ء میں ۱۴؍ اور ۱۵؍ اگست کی درمیانی رات کو ختم ہوا جب یہ ملک آزاد ہوگیا۔ ہمارے یہاں عدم تشدد کی وجہ سے اس جدوجہد میں ایک ندرت پیدا ہوگئی لیکن دنیا میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ اور اُسے حاصل کرنے کا حوصلہ قریب قریب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان۔ آج کل کی طرح زمانہ ٔ قدیم میں بھی اتحاد و تعاون کو آزادی کی جدوجہد کی کامیابی کے لئے ضروری خیال کیا جاتا تھا ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ قبیلے یا طبقے یا پیشے یا سماج کی آزادی کے لئے افراد پر پابندیاں ضروری سمجھی جاتی تھیں ۔ اس طرح آزادی اور محکومی میں مذکورہ بالا تضاد کے ساتھ ان کی پابندیوں کی شکل میں ایک مشترکہ عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
آزادی کا تصور ابتدائی دور میں
شروع میں فرد کی آزادی کا تصور اتنا واضح نہیں تھا جتنا کہ گروہ کی آزادی کا تصور اور ’’پتھر کے ابتدائی دور‘‘ میں ایک طرح کا نراج پایا جاتا تھا لیکن انسان نے پتھر کے اوزاروں کا استعمال ابھی ترک نہیں کیا تھا کہ مختلف گروہوں کے ٹکراؤ نے آزادی کے تحفظ کی خاطر اتحاد کی ضرورت نمایاں کردی ۔ اس کے ساتھ حکومت اپنی ابتدائی شکل میں اور ضبط و نظم کی تدوین اور تحفظ والی تدابیر کے ساتھ وجود میں آگئی۔ قدیم سماج میں آزادی اور مساوات کے تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ۔ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں افراد کی تعداد چونکہ کم ہوتی تھی اس لئے وہ سب ایک دوسرے سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے۔ جب فتوحات کے جذبے نے جو آزادی کے جذبے سے نکلا تھا، حکومت کے حلقہ اقتدار و اختیار کو بڑھا دیا تو حکومت اور عوام کے بیچ کا فاصلہ بہت بڑھ گیا۔ اس فاصلے کو کم کرنے اور اجتماعی فیصلوں کو ممکن بنانے یعنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے طرح طرح کے بندوبست کئے گئے۔ ان میں کئی باتیں ایسی تھیں جنہیں اُن کی موجودہ ترقی یافتہ شکل میں آزاد سماج کا جزو لاینفک کہا جاتا ہے۔
جدید حکومتوں کی طرح ان قدیم حکومتوں کو بھی اقتدار کی ہوس تھی۔ اس ہوس نے فتح مندی کا شوق پیدا کیا۔ یہ شوق اوپری طبقے تک محدود تھا اور اس طبقے نے اپنی طاقت کے ذریعے بقیہ آبادی کو اپنا فرمانبردار بنالیا۔ اس کام میں مذہب کا بھی سہارا لیا گیا۔ حکمراں کی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی کہا جانے لگا اور مذہب اور طاقت کے استعمال نے اہرام مصر جیسی عظیم الشان تعمیرات کو ممکن بنا دیا لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد غیرمطمئن رہی۔ خوف اور بے اطمینانی نے پھر آزادی کے جذبے کو ہوا دی اور جو لوگ پالتو جانوروں کی طرح خاموش کردیئے گئے وہ جنگ ِ آزادی کے میدان میں اترنے لگے ۔ لیکن جن لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا، یعنی حکمراں اور مذہبی پیشوا، وہ بھی اپنے آپ کو آزادی کا محافظ بتاتے تھے۔
آزادی اور خودغرضی
پندرہویں صدی عیسوی تک آزادی سے مراد وہ ’منفی حقوق‘ تھے جو رواجاً چلے آرہے تھے اور ان حقوق کی ، نقد کے عوض لین دین ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ رواج کو قانون کی حیثیت حاصل ہوگئی اور رواج کو توڑنا آزادی پر حملہ کرنا بن گیا۔ مگر اس تصور کا اطلاق بہت ہی محدود پیمانے پر کیا گیا۔ ایک گروہ اپنے تحفظ اور اپنی ترقی کی کوششوں میں دوسرے گروہوں کے تحفظ اور ترقی کی کوئی پروا نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ یونان کی آزاد شہری ریاست میں شہریوں کو نہ صرف ہر مسئلے کے فیصلے بلکہ ہر بڑے افسر کے تقرر پر ووٹ دینے کا حق حاصل تھا مگر عورتیں اور غلام ووٹ کے حق سے محروم تھے۔ مشرق کے بعض آزاد ملکوں میں آج بھی غلامی کا رواج پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو ووٹ کا حق نہ صرف مصر و ایران بلکہ بعض یورپی ملکوں میں بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد ملا ہے۔ برطانوی مفکر میکالے نے متوسط طبقے کے لئے ووٹ کے حق کی زبردست وکالت کرنے کے باوجود بالغ حق رائے دہی کی اتنی ہی زبردست مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح سوسائٹی کا تانہ بانہ بکھر جائے گا ۔
آزادی کے معاملے میں ایسی ہی خود غرضی کا مظاہرہ مذہبی لیڈروں اور گروہوں کی طرف سے بھی کیا گیا ۔ کسی مسلک سے انحراف کرنے والے اپنے ساتھ تو رواداری برتے جانے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن وہ خود اپنے سے مختلف عقائد کے پیروؤں کے ساتھ رواداری نہیں برتتے تھے۔ سیاستدانوں اور حکمرانوں میں یہ تضاد اور زیادہ نمایاں رہا ہے۔ جن طاقتوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اپنے مخالفوں پر دوسروں کو آزادی سے محروم کرنے کا الزام لگایا وہ خود ان جنگوں کے دوران اور ان کے بعد بھی دوسرے ملکوں پر حکومتیں کرتی رہیں ۔
انسانی سماج کی ترقی کو موٹے طور سے دو ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جب ابتدائی ڈھیلے پن کی جگہ نظم و ضبط آجاتا ہے تو ایک دور ختم ہوجاتا ہے۔ اس نظم و ضبط کے استحکام کو آزادی کے تحفظ والی تدبیر بھی کہا جاسکتا ہے اور اس کی خاطر فرد کی آزادی محدود کردی جاتی ہے۔ یہ حد بندی فوری خطرے کے پیش نظر زیادہ بری نہیں معلوم ہوتی اور نراج سے عاجز آئے ہوئے انسان قانون کی پرستش کرنے لگتے ہیں ۔ پہلے سے حاصل کی ہوئی قوت کی وجہ سے سماج اور اس کی تہذیب میں پختگی اور رس آجاتا ہے مگر حکومت پختہ ہوکر ٹھس بن جاتی ہے اور رواج اور روایات کی جکڑ بندیوں میں پھنس جاتی اور قوم نیز اس کی تہذیب کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس طرح اس کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہندوستان، چین، میسوپوٹامیا اور مصر میں ایسے حالات بیرونی حملوں کا پیش خیمہ بن گئے جن سے ان ملکوں کی آزادی ختم ہوگئی۔
یورپ میں جاگیرداری کے خاتمے کے بعد شاہی اقتدار کی مرکزیت میں اضافہ ہوگیا اور فرد کے مقابلے پر ریاست کے اختیارات برابر بڑھتے گئے۔ ایک طرف قوموں کی آزادی پر حملہ ہورہا تھا اور دوسری طرف آزادی کا ایک نیا تصور تقویت حاصل کررہا تھا جس کا تعلق فرد کی آزادی سے تھا۔ چھاپے خانے کی دریافت نے سیاسی آزادی کے عام مفہوم میں اظہار رائے کی آزادی کا تصور داخل کردیا۔ انیسویں صدی میں سرمایہ داری کے سن بلوغ کو پہنچنے تک قومی آزادی کی جدوجہد اور انفرادی آزادی کی جدوجہد ایک دوسرے کے متوازی چلتی رہیں ۔ یہ دونوں تحریکیں حصول خودی کے اس جذبے کی نشاندہی کرتی ہیں جو ہمیشہ سے آزادی کے تصور کی تہہ میں کام کرتا رہا ہے۔
فرد اور سماج
فرد کی آزادی کے تصور نے جمہوریت کے نظریے کو جنم دیا اور اگرچہ انیسویں صدی میں امن و نظم کے قیام و استحکام اور سلطنتوں کی توسیع کے لئے ’ریاست‘ یا ’مملکت‘ کے اختیارات بہت بڑھ گئے مگر سب سے نچلی منزل کے اشخاص کو چھوڑ کر سماج کے بقیہ طبقوں کو پھر بھی کافی آزادی حاصل رہی ۔ انیسویں صدی میں آزاد خیال (لبرل) ریاست کے تصور کی جگہ بیسویں صدی میں سماجی فلاحی ریاست کا تصور رائج ہونے لگا۔ آزادی کا نصب العین مساوات کے نصب العین سے آملا، سماجی انصاف کے تصور نے جنم لیا اور سوشلزم کا چرچا ہونے لگا۔
معاشی مساوات
معاشی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی کو ادھورا کہا جاتا ہے اس لئے کہ محض سیاسی آزادی سے بیشتر عوام کے جذبہ ٔ خودی کی تسکین کے علاوہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صنعتی انقلاب اور سائنس کی ترقی نے معاشی بہتات اور مساوات کو ممکن بنادیا ہے مگر ساتھ ہی بعض نئے مسئلے بھی پیدا کردیئے ہیں ۔ چیزوں کے تبادلے کا طریقہ ختم ہوجانے اور بڑے پیمانے پر چیزوں کی پیداوار کا طریقہ رائج ہوجانے سے پیداوار کے ساتھ کاریگر کا جذباتی تعلق کمزور ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی ترقی سے مفادات کے تصادم کا امکان بھی بڑھ گیا ہے۔ کوئی ذمہ دار حکومت یہ گوارا نہیں کرسکتی لیکن جب وہ مداخلت کرتی ہے تو آزادی کا نعرہ ، جو معاشی فلاح کے لئے استعمال ہونا چاہئے، معاشی غلبے کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
آزادی کے بندھن
جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جمہوری مساوات کو بھی خودداری کے منافی قرار دیتے ہیں لیکن آج کی دنیا میں زندگی اتنی پیچیدہ ہوگئی ہے کہ کسی فرد یا طبقے کو من مانی کرنے کی چھوٹ نہیں دی جاسکتی ۔ آزادی کا مطلب ہے قانون کے اندر آزادی اور قانون کی حیثیت سماج کے ضابطے، اخلاق و اطوار کی ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہر ملک میں اس کے حالات کی مناسبت سے منایا جاتا ہے اور مختلف ملکوں میں الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن مرکزیت پسندی کا رجحان عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اس سے کبھی کبھی آزادی یا کم سے کم اس کے احساس پر چوٹ پڑتی ہے۔ صوبوں کی خودمختاری اور میونسپل نظم و نسق کے طریقے اسی رجحان کی اصلاح کے لئے اختیار کئے گئے ہیں ۔
لیکن ہندوستان جیسے ملک میں ، جہاں کے صوبے بھی بعض ملکوں سے بڑے ہیں اور جہاں دیہاتوں کی تعداد شہروں سے بہت زیادہ ہے، یہ طریقے کافی نہیں سمجھے گئے ہیں اور پنچایتی راج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔
آزادی کے تصور کا ارتقاء
A
A
Related Posts
© Designed Gabfire.in - Daily Chattan